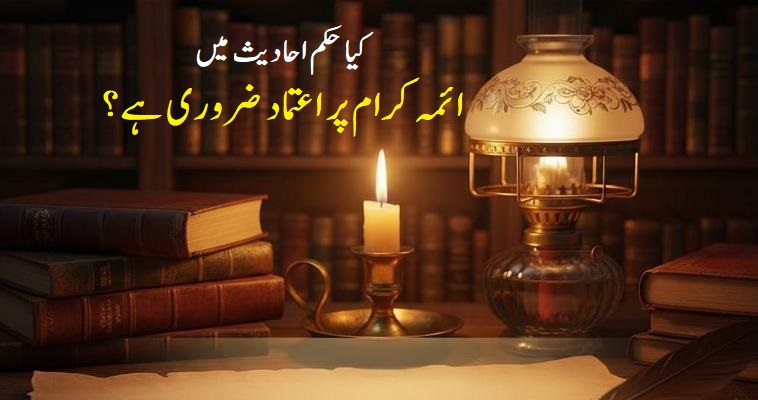مولانااسعد شاہد عطاری مدنی زِیْدَشَرْفُہ (متخصص فی الحدیث)
نگران شعبہ تدوینِ مخطوطات،مرکزخدمۃ الحدیث(دعوتِ اسلامی)
کتب ِ احادیث میں بلاشبہ بے شمار احادیثِ نبویّہ اپنی شان کے
ساتھ جلوہ پذیر ہیں، اور اُن احادیث کی حیثیت باعتبارِ صحّت و ضُعف تعیین کرنا اُمورِ مھمّہ میں سے ایک ہے تاکہ
صحیح ؛ سقیم (کمزور) سے ممتاز ہو اور ہر ایک اپنے اپنے مرتبے و شان کے لائق
مقامات میں مقبول و معمول ہو۔لیکن عصر ِ حاضر میں صحّت و ضُعف کی پہچان کے لئے کیا
طریقہ کار درست ہے؟ آیا ہر ایک کو اختیار ہے کہ فقط سند اور راویوں کی چھا ن بِین
کے بعد جس حدیث پر جو چاہے حکم لگا
دے قطعِ نظر اِس سے کہ اُس حدیث کے بارے میں اکابر ائمّہ محدّثین کی کیا رائے ہے
اور اُنہوں سے اُس پر کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ یا سب سے پہلے اُس حدیث کے متعلق
کلام ائمّہ و احکام ائمہ کو تلاش کر کے اُس سےمدد لی جائے اور اُسی کو معتمد جان
کر اُسی کا اعتبار کیاجائے؟
اِس بات کا فیصلہ کرنے کےلئے سب سے پہلے ہم
ائمّہ محدّثین متقدمین و متاخرین کی جانب سے احادیث پر لگائے گئے احکامات کی
کیفیت ملاحظہ ہو:
متقدمین
محدثین کی نقدِ حدیث میں انوکھی مہارت و قابلیت:
اللہ کریم نےائمّہ متقدمین کو
احادیث کی جانچ پڑتال میں ایسا مَلکَہ وفہم عطا فرمایا تھا کہ اِس مَلکَۂ تامّہ و
فہمِ ثاقب کی بدولت وہ احادیث کی صحّت اور اُس کے ضُعف کو پَرَکھ لیتے تھے اور
سندوں میں موجود پوشیدہ علّتوں پر مطّلع ہوجاتے تھے، اُن کی یہ معرفت الہامی ہوا کرتی
تھی حتیٰ کہ بعض اوقات اِن پوشیدہ باتوں کو الفاظ کے ذریعے تعبیر کرنے سے بھی عاجز
ہوتے تھے ، ملاحظہ ہو:
قَالَ
السّيُوطِي: وَرُبَّمَا تَقْصُرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ عَنْ إِقَامَةِ
الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ، كَالصَّيْرَفِيِّ فِي نَقْدِ الدِّينَارِ
وَالدِّرْهَمِ. امام سیوطی علیہ
الرحمہ فرماتے ہیں: ”بسا اوقات حدیث کو معّلل قرار دینے والے
کی عبارت اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے سے قاصر ہوتی ہے جیسا کہ تاجر درہم و دینار
کو پَرَکھنے کے معاملے کوبذریعہ الفاظ بتانے سے قاصر ہوتا ہے۔“
قَالَ ابْنُ
مَهْدِيٍّ: فِي مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ إِلْهَامٌ، لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِمِ
بِعِلَلِ الْحَدِيثِ: مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟ لَمْ يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ، وَكَمْ
مِنْ شَخْصٍ لَا يَهْتَدِي لِذَلِكَ.
امام عبد الرحمن بن مہدی علیہ
الرحمہ فرماتے ہیں: ”حدیث میں موجود علّت کی معرفت اِلہامی ہوا
کرتی ہے، اگر تم کسی عِلَلِ حدیث میں مہارت رکھنے والے سے پوچھو گے کہ تم نے یہ
بات کیسے کہی؟ تو اُس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی جبکہ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اِس
بات تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔
وَقِيلَ
لَهُ أَيْضًا: إِنَّكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ: هَذَا صَحِيحٌ، وَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ،
فَعَن مَنْ تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَتَيْتَ النَّاقِدَ،
فَأَرَيْتَهُ دَرَاهِمَكَ، فَقَالَ: هَذَا جَيِّدٌ وَهَذَا بَهْرَجٌ، أَكُنْتَ
تَسْأَلُ عَنْ مَنْ ذَلِكَ، أَوْ تُسَلِّمُ لَهُ الْأَمْرَ؟ قَالَ: بَلْ أُسَلِّمُ
لَهُ الْأَمْرَ، قَالَ: فَهَذَا كَذَلِكَ، لِطُولِ الْمُجَالَسَةِ
وَالْمُنَاظَرَةِ وَالْخِبْرَةِ.
امام عبد الرحمن بن مہدی علیہ الرحمہ سے ہی عرض کی گئی: آپ کسی حدیث کے متعلق کہتے ہیں: ”یہ
صحیح ہے، اور یہ ثابت نہیں۔“ تو یہ کس سے سُن کر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کیا
خیال ہے کہ جب تم کسی ناقد کے پاس جاکر اُسے دَرَاہِم دکھاؤ تو وہ کہتا ہے: یہ
جید (خالص) ہے اور یہ ردّی (ملاوٹی) ہے، تو کیا
تم اُس سے یہ کہتے ہو کہ یہ تمہیں کس نے
بتایا؟ یا اُس کی بات مان لیتے ہو؟“ اُس نے عرض کی : ”جی میں مان لیتاہوں۔“ تو آپ نے فرمایا: ”یہاں بھی طُولِ
مُجالَسَت(کثرتِ مَشق)، مناظرہ اور ذہانت کے سبب ایسا ہی ہے۔“
وَسُئِلَ
أَبُو زُرْعَةَ: مَا الْحُجَّةُ فِي تَعْلِيلِكُمُ الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ:
الْحُجَّةُ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لَهُ عِلَّةٌ فَأَذْكُرَ عِلَّتَهُ
ثُمَّ تَقْصِدَ ابْنَ وَارَةَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَيَذْكُرَ عِلَّتَهُ ثُمَّ
تَقْصِدَ أَبَا حَاتِمٍ فَيُعَلِّلَهُ، ثُمَّ تُمَيِّزَ كَلَامَنَا عَلَى ذَلِكَ
الْحَدِيثِ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَنَا خِلَافًا، فَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنَّا
تَكَلَّمَ عَلَى مُرَادِهِ، وَإِنْ وَجَدْتَ الْكَلِمَةَ مُتَّفِقَةً فَاعْلَمْ
حَقِيقَةَ هَذَا الْعِلْمِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ،
فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ إِلْهَامٌ.
امام ابو زُرْعَہ رازی سے سوال ہوا: آپ
حضرات جب کسی حدیث کو معلّل قرار دیتے ہیں تو اِس پر دلیل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا : ”دلیل یہ ہے کہ تم
مجھ سے کسی حدیث کے متعلق سوال کرو جس میں کوئی علّت پوشیدہ ہو، میں تمہیں وہ علّت
بتادوں ، پھر تم ابنِ وَرَاۃ رحمۃ اللہ
علیہ کے پاس جاؤ اُن سے پوچھو وہ بھی
علّت بتادیں، پھر تم ابو حاتِم رحمۃ اللہ
علیہ کے پاس جاؤ وہ بھی علّت بیان کردیں، پھر تم اُس حدیث کے متعلق تمام کلام میں
غور کرو، اگر تم ہمارے مابین فرق پاؤ تو سمجھ جانا کہ ہر ایک نے اپنی مرضی سے
کلام کیا ہے،لیکن اگر سارے متّفق ہوں تو
اِس علم کی حقیقت پر یقین کر لینا۔“ تو اُس شخص نے ایسا ہی کیا اور اُن تمام کے
کلام کو متّفق پایا، تو کہا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ علم اِلہَامِی ہے۔“ (تدريب الراوی،1/
296-297)
متاخرین
میں اس صلاحیت کا فقدان:
بلا شبہ ایسی نایاب مہارت وقابلیت فقط اُن
متقدمین کا ہی خاصّا تھا، متاخرین اگر چہ اپنی بَساط و استطاعت کے مطابق ذُروَۂ
اعلیٰ (بلندی) کو پہنچے لیکن متقدمین کےہم
درجہ نہ ہوسکے ۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابنِ صلاح علیہ الرحمہ نے ساتویں سنِ ہجری میں اپنے زمانے کے لوگوں کو تصحیحِ احادیث سے منع فرمایا
اور ان کے لئے یہ کام عدمِ صلاحیت کے سبب متعذر (مشکل) قرار دیا:
قال ابنُ
الصلاح: إذا وَجَدْنَا فيما يُروى مِن أجزَاءِ الحَدِيثِ وَغَيرِهَا حديثًا صحيحَ
الإِسناد وَلَمْ نجدْه في أحدِ (الصحيحَينِ) ولَا مَنصُوصًا على صِحّتِهِ في شيءٍ
من مُصَنَّفَاتِ أئمَةِ الحَدِيثِ المُعتَمَدَةِ المَشهُورَةِ، فإنّا لا نَتَجَاسَرُ
على جَزْم ِ الحُكم بِصِحَّتِهِ فَقَدْ تَعذَّرَ في هذه الأعصَارِ الاستقلالُ
بإدراكِ الصّحيحِ بمُجَرَّدِ اعتبارِ الأسَانِيدِ. امام ابنِ صلاح نے فرمایا: ”جب کوئی مروی حدیث ایسی
ہو کہ جو سند کے اعتبار سے صحیح ہو، لیکن صحیحین میں موجود نہ ہو اور نہ ہی ائمّہ
محدثین کی معتمد اور مشہور تصانیف میں سے کسی میں اُس کی صحّت پر تصریح ہوتو ہم اُس
کی صحّت پر جَزمی حکم کرنے کی جَسَارت نہیں کرسکتے، کیونکہ آج کے زمانے میں وہ
صلاحیت متعذر ہوچکی ہے کہ محض سند کے ذریعے حدیث کی صحّت کو پہچان لیں۔“(مقدمہ ابن الصلاح،ص16-17)
امام بدر الدین ابنِ جماعہ علیہ الرحمۃ نے ”خلاصہ مقدمہ ابن الصلاح“ میں امام ابنِ صلاح علیہ الرحمہ کی متابعت کی
اور اِسے برقرار رکھا: قَالَ فِي الْمَنْهَلِ الرَّوِيِّ: مَعَ
غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَمَا أَهْمَلَهُ أَئِمَّةُ
الْأَعْصَارِالْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِشِدَّةِ فَحْصِهِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ. آپ نے فرمایا: کیونکہ اِس بات پر غلبۂ
ظنّ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہی ہوتی تو پچھلے زمانے کے ائمّہ کرام اِس پر ضرور حکم
لگاتے کیونکہ اِن کی چھان بِین اور اجتہاد کا معیار بہت سخت تھا۔ (تدريب الراوی ،1/ 157)
بلکہ امام ابنِ صلاح نے فقط تصحیح نہیں، تحسین وتضعیف کو بھی متعذر
قرار دیا جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے اُن کے کلام سےاخذ کیا: قال السيوطي: فَالْحَاصِلُ
أَنَّ ابْنَ الصَّلَاحِ سَدَّ بَابَ التَّصْحِيحِ وَالتَّحْسِينِ وَالتَّضْعِيفِ
عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْأَزْمَانِ لِضَعْفِ أَهْلِيَّتِهِمْ. امام سیوطی نے فرمایا: تو خلاصہ یہ
نکلا کہ ابنِ صلاح نے آج کے لوگوں پر حدیث کی تصحیح، تحسین اور تضعیف تینوں
دروازوں کو بند کردیا۔ (تدريب الراوی ،1/ 162)
متاخرین
میں سے حُذّاق ائمّہ کے لئے استثناء:
البتہ اِس کے بعد دیگر ائمّہ محدثین مثلِ
امام نووی، امام عراقی، امام بُلقِینی ، حافظ ابن حجر علیہم الرحمۃ وغیرہم نے اِن
کے اِس قول میں کچھ مُستَثنِیات کو بیان فرمایا کہ یہ حکم کلّی نہیں بلکہ اس میں کچھ گنجائش ہے۔
اگر متاخرین میں کوئی ایسا حاذق ماہر حافظ ناقد ہو کہ جو فنِ حدیث و اصول ِحدیث میں رُسوخ و تَبحّر (مہارت) اور نظرِ تامّ رکھے تو اس کے لئے احادیث پر احکام لگانا
جائز ہے:
قَالَ
النّوَوِی: والأظهَرُ عِندِي جَوَازُهُ لِمَن تَمَكَّنَ وَقَوِيَتْ مَعرِفَتُه،
والله أعلم.
امام نووی نے فرمایا: ”میرے نزدیک اظہر یہی ہے کہ جو قادر ہو اور
اسکی معرفت پختہ ہو تو اُس کے لئے تحکیم جائز ہے۔“ (التقريب والتيسير للنووی،ص:
28)
قال
البُلقینی: والمختارُ أنّ المُتَبحِّرَ في هذا الشَّأنِ له ذَلِكَ بِطُرُقِه التي
تَظْهَرُ لَه.
امام بُلقِینی نے فرمایا: ”مختار یہی ہے کہ اِس فن میں متبحّر شخص کے
لئے تحکیم جائز ہے اُن سندوں کو مطابق جو اُس تک پہنچے۔“ (مقدمۃابن الصلاح ومحاسن
الاصطلاح ،ص 159)
اِسی طرح جب حکم لگائے تو مطلقاً حکم نہ
لگائے بلکہ اُس حدیث کی سند پر حکم لگائے کہ سندکے اعتبار سے یہ حدیث صحیح یا حسن
ہے، متن کے صحت و ضُعف کا دعویٰ نہ کرے (مثلا: هذا حديث صحيح الاسناد، هذا حديث
حسن الاسناد وغیرہ) ممکن ہے کہ
متن میں کوئی ایسی مخفی علّت موجود ہو جس
تک اُس کی رَسائی نہ ہو سکی ہو، یا اُس حدیث کی کوئی دوسری سند بھی موجود ہوجس کو
یہ ضعیف قرار دے رہا ہے۔
قال السیوطي:
وَالْأَحْوَطُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِصَحِيحِ الْإِسْنَادِ،
وَلَا يُطْلَقُ التَّصْحِيحُ لِاحْتِمَالِ عِلَّةٍ لِلْحَدِيثِ خَفِيَتْ عَلَيْهِ،
وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ يُعَبِّرُ خَشْيَةً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَحِيحٌ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. امام
سیوطی نے فرمایا: ”اِس جیسی صورت میں احوط(زیادہ محتاط انداز) یہی ہے کہ حدیث
کو ”صحیح
الاسناد“ سے تعبیر کیا جائے
مطلقاً صحیح قرار نہ دیا جائے، کیونکہ اِس بات کا احتمال موجود ہے کہ اُس حدیث میں
کوئی ایسی علّت ہو جو اُس پر مخفی رہ گئی ہو۔ اور میں نے بعض کو دیکھا ہے جو اسی احتیاط کے
پیشِ نظر حدیث پر ”صحیح اِنْ شاء الله“ کا اطلاق کرتے ہیں۔ (تدريب الراوی،1/ 161)
قال أيضاً: وَقَدْ
مَنَعَ فِيمَا سَيَأْتِي وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ أَنْ
يَجْزِمَ بِتَضْعِيفِ الْحَدِيثِ اعْتِمَادًا عَلَى ضَعْفِ إِسْنَادِهِ،
لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ غَيْرُهُ. آپ نے یہ بھی فرمایا: ”اور امام ابنِ صلاح
نے ممنوع قرار دیا (اور مصنّف امام نووی وغیرہ نے اِن کی موافقت کی) اِس بات کو کہ
محض سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے کسی حدیث کے ضعیف ہونے پر جَزمی حکم کر دیا جائے ،
کیونکہ ممکن ہے اس حدیث کی کوئی دوسری صحیح سند بھی موجود ہو۔“ (تدريب الراوی (1/ 162)
متاخرین
کے لئے حدیث کو موضوع قرار دینا بدرجہ اولیٰ ممنوع:
یہ ساری گفتگو احادیث کی تصحیح، تحسین اور تضعیف
کے متعلق تھی، رہی بات متاخرین کے لئے حدیث پاک کو موضوع قرار دینے کی تو وہ
تو ائمہ کرام نے بدرجۂ اولیٰ ممنوع قرار
دیا کہ حدیث پاک کو موضوع قرار دینے کے
لئے جو قرائن (دلائل) درکار ہیں ان پر اطّلاع متاخرین کے لئے ممکن ہی نہیں، اِلَّا
یہ کہ اُس حدیث میں قرائنِ عامّہ (یعنی وہ قرائن جن کے ادراک پر متقدمین و متاخرین
دونوں شریک ہوتے ہیں) پائے جائیں۔ (اِن قرائن کی تفصیل اعلیٰ حضرت کے رسالہ منیر العین میں موجود ہے)
قال
السیوطی: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْوَضْعِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ قَطْعًا إِلَّا
حَيْثُ لَا يَخْفَى؛ كَالْأَحَادِيثِ الطِّوَالِ الرَّكِيكَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الْقُصَّاصُ،
أَوْ مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْعَقْلِ أَوِ الْإِجْمَاعِ. امام سیوطی نے فرمایا: ”بلاشبہ حدیث پر وضع کا قطعی (موضوع ہونے کا یقینی) حکم لگانا بدرجہ
اولیٰ ممنوع ہے مگر جہاں موضوع ہونا واضح ہو، مثلاً وہ لمبی لمبی رکیک (کمزور
الفاظ والی) احادیث جنہیں قصہ گو نے وضع
کیا ہو، یا جو احادیث عقل یا اجماع کے
خلاف ہو۔“ (تدريب الراوی ،1/ 162)
قال
العَلَائِي: الحُكمُ عَلَى الحَديثِ بِكَونِهِ مَوضُوعاً مِن المُتَأخّرِينَ عُسرٌ
جِدّاً، لأنّ ذَلِكَ لا يَتَأتَّى إلا بَعدَ جَمعِ الطُّرُقِ وكَثرَةِ التّفتِيشِ
وإنّه لَيسَ لِهَذا المَتنِ سِوَى هَذِهِ الطَّرِيقِ. امام عَلَائی نے فرمایا: ”متاخرین کی جانب سے
حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانا انتہائی مشکل امر ہے۔ کیونکہ ایسا اُس حدیث کے
تمام طُرُق (اسانید) کو جمع کرنے اور کثرتِ تفتیش کے بعد ہی ممکن ہے۔ اور پھر یہ
یقین ہو کہ اِس کے علاوہ اِس حدیث کی کوئی اور سند ہے ہی نہیں۔“ (النقد الصحيح لما اعترض من
أحاديث المصابيح ،ص 24)
اِس کے علاوہ کثیر نصوص ہیں جو یہ واضح کرتی
ہیں کہ متاخرین کے لئےحدیث کو قطعی طور پر موضوع قرار دینا ممنوع ہے۔
کیا
معاصرین اِس کام کی اہلیت رکھتے ہیں؟
معلوم ہوا کہ احادیث پر صحت، ضعف اور وضع
وغیرہ کا حکم لگانا دراصل متقدمین محدثین کا کام تھا جن کی معرفتِ حدیث اِلہامی
تھی اور حدیث اُن کی غِذا تھی، متاخرین میں ضُعفِ اہلیت کے سبب یہ امر ممنوع قرار
پایا۔ ہاں اگر متاخرین میں سے کوئی ایسا جِہبِذ (ماہر) ہو جو فنِ حدیث میں اطّلاعِ تام رکھتا ہو تو
اُس کے لئے احادیث کی سند پر حکم لگانا جائز ہے۔ لیکن وہ بھی صحت و ضعف کی حد تک،
حدیث پاک کو موضوع قرار دینے کے لئے قرائنِ
خاصّہ خفیہ (وہ قرائن جن کے ادراک پر صرف متقدمین قادر
ہوتے ہیں) کا ادراک اُن کے لئے
بھی ممکن نہیں، فقط قرائنِ عامہ کا ادراک ممکن ہے۔ یہ بات بھی متاخرین جَہابِذہ (ماہرین) کی ہے، وہ
جَہابِذہ کہ بغیرکسی ڈیجیٹل ذرائع کے کتب و مصنفین پر اُن کی نظر اتنی وسیع ہوا
کرتی تھی کہ آج بھی دیکھ کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیا شاملہ اور کیا گوگل!
یقین نہ آئے تو بطورِ نمونہ کتاب ”فہرس
الفہارس والاثبات“ اور ”الرسالۃ المستطرفۃ“ اور اِن جیسی دیگر کتب دیکھ لی جائیں۔
لہٰذا
وہ معاصرین کہ جن کی ساری تحقیقات، سارا
مواد ، نیٹ اور شاملہ کے سہارے چلتا ہے اُن
کا کیا حال ہوگا؟ اور اُن کا حدیث پر حکم لگانے کے متعلق کیا حکم ہوگا اِس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔
دورِ
حاضر میں حدیث پر کس طرح حکم لگایا جائے؟
لہٰذا یہ بات اب واضح ہے کہ عصر ِحاضر میں
اگر کوئی کسی حدیث کی فنی حیثیت معلوم
کرنا چاہے تو وہ بذات خود نئے سِرے سے
تحقیق کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اُس کا
سارا دار و مدار ائمّہ محدثین (متقدمین و متاخرین) کی جانب سے کی گئی تحقیقات اور احادیث پر لگائے گئے احکام و کلام پر ہونا چاہئے،کیونکہ
دورِ حاضر کے افراد میں اتنی سَکَت ہے ہی نہیں کہ محدثین کی اتباع و پیروی کیے
بغیر فقط اپنی اَٹَکل سے حدیث پاک پر حکم لگا سکیں۔
اب جب بھی کسی حدیث کے متعلق صحت و ضُعف کی
جانچ کرنی ہو تواُن کتب محدثین کی طرف رجوع کیا جائے گا جن میں انہوں نے احادیث پر
احکام لگائے ہوں یا کچھ کلام کیا ہو (مثلا سنن ترمذی،
مستدرک ، مجمع الزوائد،المقاصد الحسنۃ وغیرہ ،اور اسکے علاوہ اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں)
کلام
ائمہ کے متعلق مختلف صورتیں:
بعض اوقات کسی حدیث کے متعلق کلامِ ائمّہ
آسانی سے مل جاتے ہیں اور اُن کے مطابق فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات
کلام ائمّہ باوجود کثیر تلاش کے نہیں ملتے، یا ملتے ہیں تو مختلف ائمّہ کے کلام آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسکی صورتیں اور اور اُن کے متعلق حکم ملاحظہ
ہو:
اول: اگر محدثین کی جانب سے لگائے گئے احکامات یکساں ہوں اور کسی طرح کا
اختلاف نہ ہو،تو معاملہ آسان ہےکہ جو حکم وہاں موجود ہوگا وہی معتبر مانا جائے
گا۔
ثانی:اگر اُن کتب میں ایک ہی حدیث کے متعلق ائمّہ کرام کے کلام مختلف ہوں، مثلا ایک جانب کسی
امام نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہواور
دوسری جانب کسی اور نے ضعیف، تو ایسی صورت
میں ترجیح کا طریقہ اختیار کیاجائے گا۔ جیسا کہ علامہ عبد الحی لکھنوی علیہ الرحمۃ نے ”ظفر الامانی“ میں بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ
ہو:
وأمّا إِذَا
اختَلَفُوا فِيمَا بَينَهُم فَالأَمْرُ عَسِيرٌ وَالاختِلَافُ فِيمَا بَينَ
جَهَابِذَةِ الحَدِيثِ فِي هَذَا البَابِ غَيرُ قَلِيلٍ وعِندَ ذَلِكَ يُطلَبُ
التَّرجِيحُ بِوَجهٍ مِن الوُجُوهِ فَيُؤخَذ بِالمُرَجَّحِ ويُترَكُ مَا سِوَاهُ.
وله طُرُقٌ كَثِيرَةٌ:
مِنهَا أن
يُدَقَّقَ النَّظرُ فِيمَا قَالَهُ الفَرِيقَانِ وَيُنظَرَ فِيمَا به حَكَمَ
بَعضُهُم بِالوَضعِ أو بِالضّعفِ وبَعضُهُم بِالصِّحَّةِ بِنَظرِ التَّأمُّلِ
والعِرْفَانِ فَيُؤخَذ بِمَا وَضَحَتْ صِحَّتُهُ ويُترَك مَا ظَهَرَ سَقِيمُهُ.
ومِنهَا أنْ
يَكُونَ صاحب أحد القَولَينِ مُتساهِلاً في التَّحسِينِ والتَّصحِيحِ والآخَرُ
مُنقِّحاً ومُفَتِّشاً مُهتَمّاً بِالتَّحقِيقِ والتَّنقِيحِ فَحِينَئِذٍ يُرجَّح
قولُ غَيرِ المُتَسَاهِلِ على قَولِ المُتَسَاهِلِ كالحَاكِمِ صَاحِبِ
المُستَدرَكِ فإنَّهُم بِأجْمَعِهِم نَصُّوا عَلَى أنّهُ لا اعتِمَادَ عَلَى
تَصحِيحِهِ.
ومِنهَا أنْ
يَكُونَ صَاحِبُ أَحَدِ القَولَينِ من المُبَالِغِينَ في الجَرحِ والآخَرُ
مُتَوسِّطاً ومُعتَدِلاً فِي القَدَحِ فيُرَجَّح قَولُ غَيرِ المُتَشدِّدِ على
قَولِ المُتَشَدِّدِ ويُقبَل تَصحِيحُ المُتَوسِّطِ وتَحسِينُهُ دُونَ تَضعِيفِ
المَشَدِّدِ وحُكمِ وَضعِهِ.
ومِنهَا أنْ
يَكُونَ صَاحِبُ أحَدِ القَولَينِ مِنَ المُشَدِّدِينَ فِي الحُكمِ بِالوَضعِ
والضُّعفِ كابنِ الجَوزِيِّ.... وَالآخَرُ من المُتَوَسِّطِينَ المُنَقِّحِينَ
كابنِ حَجَر العَسقَلانِيّ وشَيخِهِ العِرَاقِيّ والسُيُوطِيّ وأشبَاهِهِم
فَحِينَئِذٍ يُرَجَّح قَولُ الآخَرِينَ عَلى الأوَّلِينَ ولا يُبَادَر إلى الحُكمِ
بِالضُّعفِ والوَضعِ بِمُجَرَّدِ حُكمِ الأوّلِينَ.
ترجمہ: بہر حال جب کلام ائمّہ آپس میں مختلف ہوں (اور درحقیقت اُن جَہَابِذہ کے مابین اختلاف کم تعداد میں نہیں) تو ایسی صورت میں وجوہ ِترجیح میں سے کسی
وجہ کو تلاش کیا جائے گا، اور راجح کو
اختیار کر کے ماسویٰ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسکے کثیر طریقے ہیں:
ایک یہ کہ دقّتِ نظری کے ساتھ دونوں جانب كے اقوال دیکھے
جائیں اور خوب غور و فکر کر کے اُن احادیث کو دیکھا جائےجن پر ایک نے وضع یا ضُعف
کا حکم لگایا ہے اور دوسرے نے صحت کا۔ تو جس قول کی درستگی واضح ہو اُسے اختیار
کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔
دوسرا یہ کہ اُن دو قائلین میں سے ایک حدیث کو صحیح و حسن
قرار دینے میں مُتساہِل (نرمی برتنے والا) ہو اور دوسرا مُنقِّح و مفتّش ہو اور تحقیق
و تنقیح کا اہتمام رکھنے والا ہو۔ تو ایسی صورت میں غیر مُتساہِل کا قول مُتساہِل
کے مقابلے میں مقبول ہوگا۔ مثلا امام حاکم( صاحبِ مستدرک)کے بارے میں تمام محدثین نے یہ صراحت کی ہے
کہ اِن کی تصحیح پر اعتماد نہیں۔
تیسرا یہ کہ دو قائلین میں سے ایک جَرح میں مبالغہ کرنے والا
ہو جبکہ دوسرا جَرح کرنے میں متوسّط و معتدل ہو۔ تو غیر متشدّد کا قول متشدّد کے
مقابلے میں راجح ہوگا اور متوسّط کی جانب سے تصحیح و تحسین مقبول ہوگی نہ کہ متشدّد
کی جانب سے تضعیف اور حکمِ وضع۔
چوتھا یہ کہ دو قائلین میں سے ایک وضع اور ضُعف کا حکم لگانے
میں متشدّد ہو مثلاً امام ابن الجوزی۔۔۔۔۔ اور دوسرا متوسّطین اور منقّحین میں سے
ہو مثلاً امام ابنِ حجر عسقلانی اور اِن کے شیخ امام عراقی اور امام سیوطی وغیرھم۔
تو ایسی صورت میں متوسّطین کا قول راجح ہوگا متشدّدین کے مقابلے میں اور محض متشدّدین
کی جانب سے حکم دیکھ کر حدیث کے ضُعف و وضع کا فیصلہ نہیں کر لیا جائے گا۔
کیا
یہ طریقۂ ترجیح بھی ہر ایک کے بس میں ہے؟
یہاں ایک اور امر توجہ طلب ہےوہ یہ کہ ائمّہ
کرام کے کلاموں کے مابین اختلاف کو حل کرنے کے لئے ترجیح کے طریقے کار کو اختیار
کرنا بھی ہر ایک کےبس میں نہیں جیسا کہ امام لکھنوی علیہ الرحمہ نے اِس صورتحال کو
امرِ عسیر (مشکل ترین امر)قرار دیا۔ کیونکہ اِس کے لئے خوب دقّتِ نظری اور غور و
فکر چاہئے اور پھر محدثین اور کتبِ محدثین کے مناہج و صفات پر گہری نظر
چاہئے کہ فلاں امام متشدّد ہے فلاں امام
متوسط ہے، اور فلاں کتاب کی یہ خصوصیت ہے اور فلاں کی یہ وغیرہ وغیرہ ۔ فقط اپنی رِضا
و خواہش سے جس قول پر دل جَمے اُس قول کو
اختیار کر لینا اور باقی کو ترک کردینا
کسی جرأت سے کم نہیں ہوگا۔
کسی
کا یہ کہنا: ”کسی محدث کا حکم ہمارے لئے پتھر پر لکیر نہیں ہوتا“
یہی سے یہ بات ہر اَنکھیارے (آنکھ
والے) کے لئے اَظْہَر مِنَ الشَّمس (سورج سے زیادہ
روشن) ہو گئی کہ اختلاف کی صورت
میں جب کسی ایک اما م کے قول کو اختیار کر کے مرجوح قول کو ترک کر دیا جائے تو
متروکہ قول کے بارے میں ہر گز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ”چونکہ کسی محدث کا حکم
ہمارے لئے ”پتھر پر لکیر“ نہیں ہوتا اس لئے اس قول کو چھوڑ دیا گیا۔“ کیونکہ در حقیقت اِس قول کو اِس وجہ سے ترک نہیں
کیا گیا کہ اِس قول پر اعتماد نہیں تھا بلکہ اِس وجہ سے ترک کیا گیا کہ اِس قول کے مقابلے میں ایک دوسرا قول موجود
تھا اور پھر وجوہِ ترجیح میں سے ایسی وجہِ
ترجیح پائی گئی کہ جس نے اُس قولِ مقابِل کو راجح قرار دیا اور اِسے مرجوح۔جیسا کہ امام حاکم
علیہ الرحمہ کی تصحیح اور اُس کے مقابلے میں امام ذہبی کی تضعیف، ایسے ہی امام ابنِ
جوزی علیہ الرحمہ کی جانب سے حکمِ وضع اور اُس کے مقابلے میں امام سیوطی علیہ
الرحمہ کا تعقب۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔
اور پھر اگربطورِ تسلیم کسی محدّث کا حکم ہمارے لئے معتمد ہے ہی نہیں
تو پھر کس طرح کسی حدیث کی فنی حیثیت کوجانا جائے؟ وہ مہارت وقابلیت کہاں سے حاصل
کی جائے کہ جو محض ائمّہ محدثین کا ہی خاصّہ تھا؟ کسی حدیث پر صحت و ضُعف کاحکم
لگانا کتنا دشوار ترین امر ہے اور کِن کِن منازِل کو طے کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ
کے رسالے ”الفضل الموھبی“ میں بیان کردہ
منازل سے لگانا چاہئے۔ مزید یہ کہ اگر اُن
کے احکام معتبر ہے ہی نہیں تو کیا اُن کی جانب سے کی گئی تحقیقات کا فائدہ فقط اتنا ہے کہ قیامت تک کتابوں کی زینت بنی رہے؟ نہ اُن پر اعتماد نہ
اعتبار اور عمل تو کُجَا!
ثالث: اگر
اُس حدیث کے متعلق کلام ائمّہ باوجود بحث و تفصیح کے ملے ہی نہیں تو اب ضرورت کے پیشِ نظر اپنی استطاعت و حیثیت
کے مطابق حکم صادر کیا جائے گا اور یہ کام
بھی اُن معاصرین مشتغلین بِعِلم الحدیث (علمِ حدیث میں
مشغول علما) کا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اِ س فن میں وقف کردی
ہواور کلامِ محدثین و کتبِ محدثین میں
کثرتِ ممارست رکھتے ہوں، تو وہ راویوں کی تحقیق کے ذریعے محض سند پر صحت وضُعف کا
حکم لگا سکتے ہیں، اور موضوع کاحکم فقط قرائنِ عامّہ کے ذریعے لگا سکتے ہیں (یعنی اُن قرائن کے ذریعے جن کے ادراک پر
متقدمین ومتاخرین دونوں شریک ہوتے ہیں) لیکن یاد رہے یہ تب ہے کہ جب اُس
حدیث کے متعلق کلام ائمّہ باوجود کثرتِ تلاش کے نہ ملے، ورنہ سب سے پہلے کلامِ ائمہ کو تلاش کیا جائے گا اور
وہی پہلی ترجیح ہوگی۔
خلاصۂ
بحث:
سابقہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ حدیث پر تحکیم
آسان امر نہیں۔ یہ اکابر متقدمین محدثین
کا کام تھا، عصر ِ حاضر میں اہلیت و قابلیت کے
فُقدَان کے سبب حدیث کی فنی حیثیت کو جاننے کے لئے اُن محدثین کے اقوال کی طرف ہی
رجوع کیا جائے گا اور اُسی کے مطابق صحت و ضُعف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر
بالفرض کسی حدیث کے متعلق کلام ائمہ نہ ملے تو احتیاج کے پیشِ نظر حدیث کی
سند پر حکم لگایا جا سکتا ہے بشرط یہ
کہ حکم لگانے والا اِس فن میں کثیر مہارت و مُمارَست رکھتا ہو اور مناہجِ محدثین و
کتبِ محدثین سے واقف ہو، نیٹ، شاملہ اور دیگر سرچ انجن سافٹ ویئرز کے سہارے اُس کی گاڑی نہ چلتی ہو۔ والله أعلم
 Dawateislami
Dawateislami